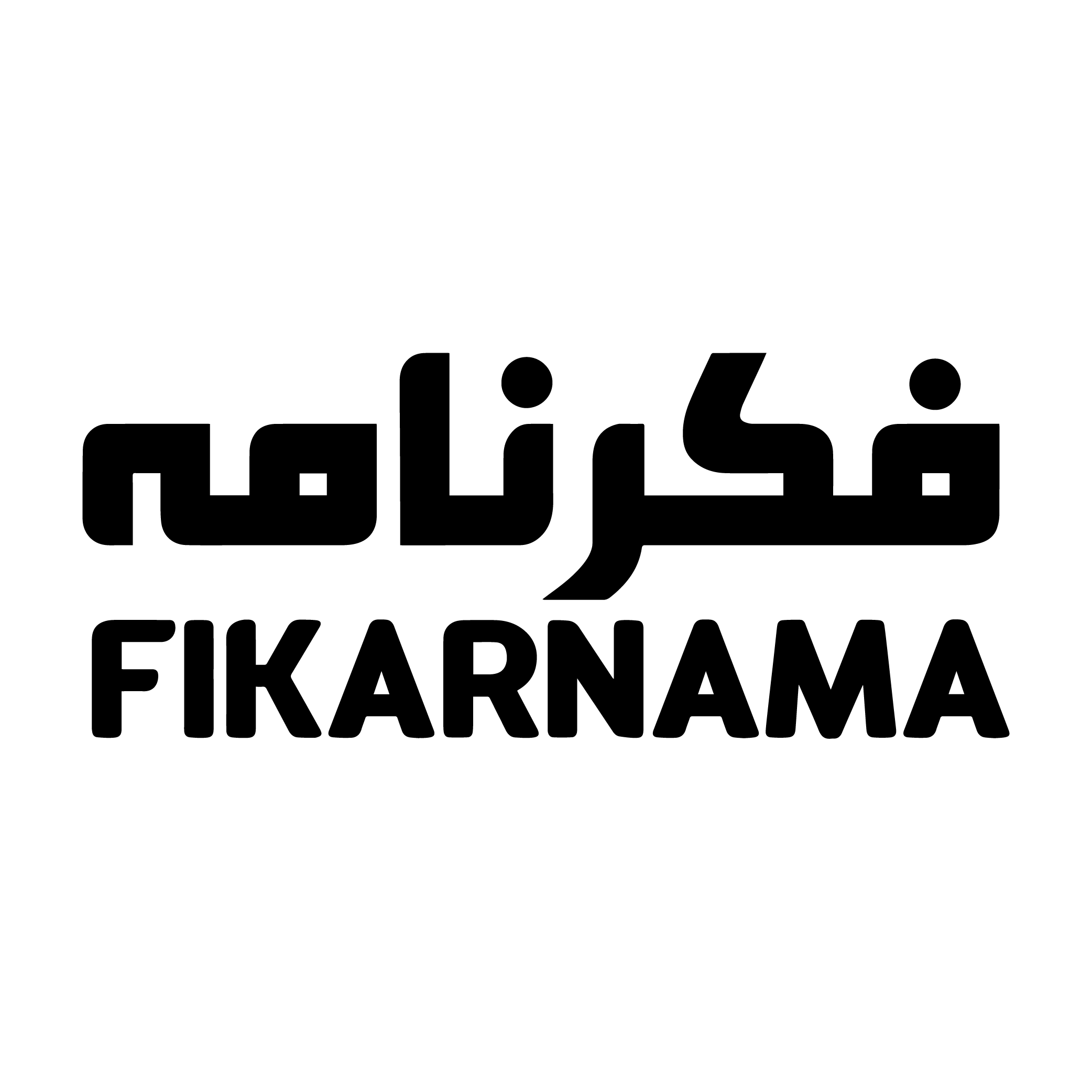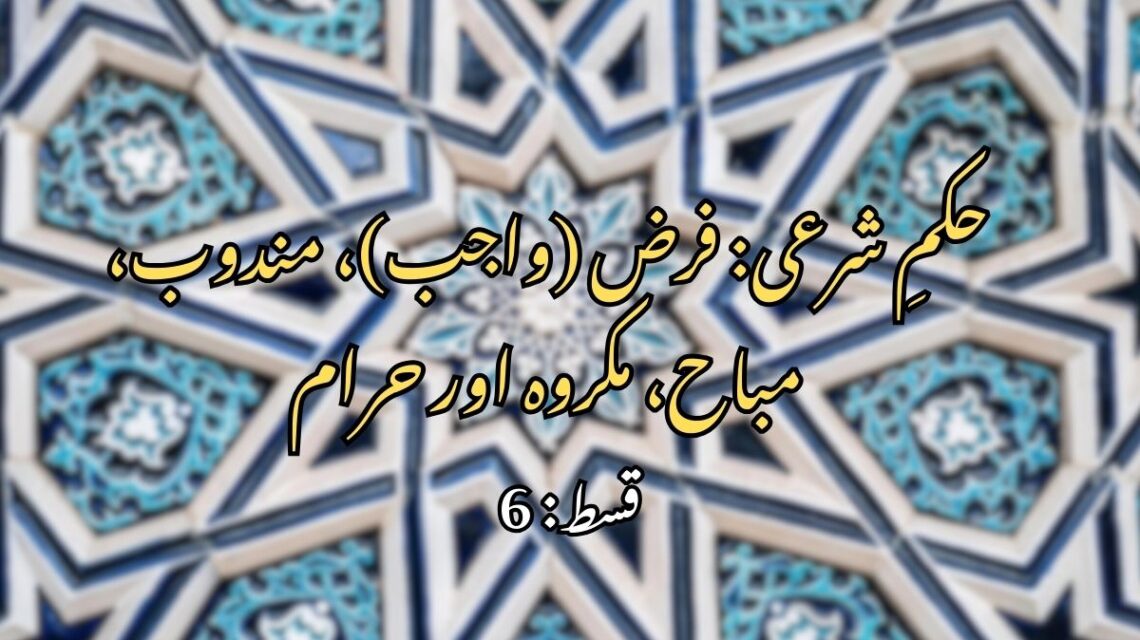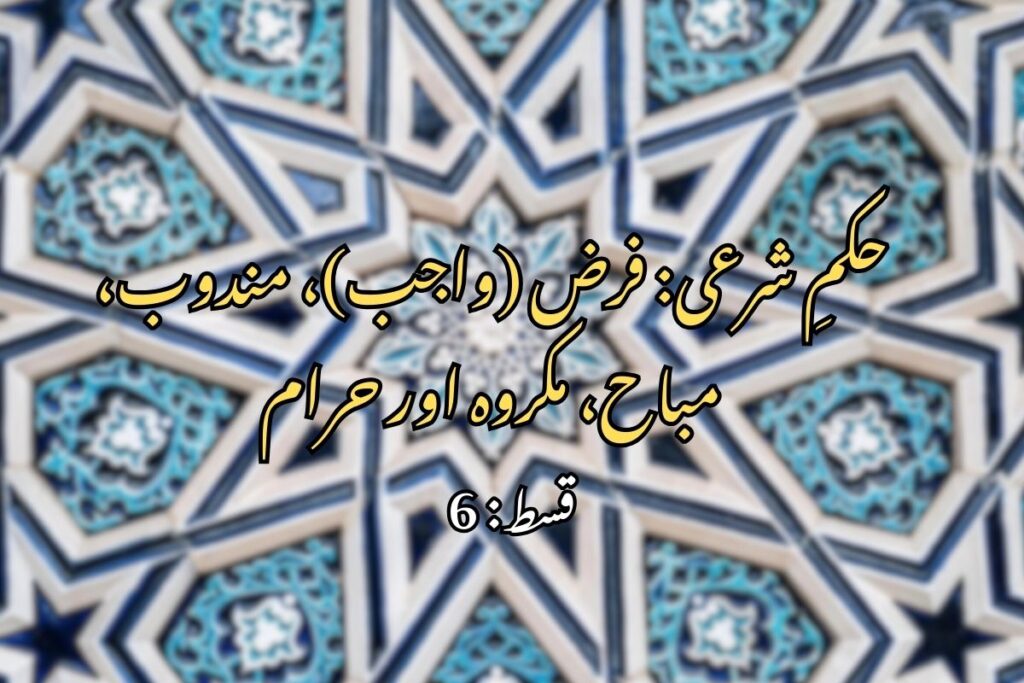
حکمِ شرعی کی تعریف:
خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد بالإقتضاء أو بالتخییرأو بالوضع (بندوں کے افعال سے متعلق شارع کا وہ خطاب جو طلب یا اختیار دینے یا وضع کے ساتھ کیا گیا ہے) اگرچہ شارع اللہ تعالیٰ ہے مگر یہاں خطاب اللہ کے بجائے خطابِ شارع اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ کہیں یہ وہم نہ ہو کہ اس سے مراد فقط قرآن ہے۔ سنت بھی چونکہ وحی ہے اس لئے وہ بھی خطابِ شارع میں شامل ہے اور اجماعِ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی کیونکہ اس سے مراد سنت سے کسی دلیل کا انکشاف ہے۔ مکلف کے بجائے بندہ اس وجہ سے کہا گیا کیونکہ اس میں بچے اور پاگل سے متعلقہ احکام بھی شامل ہیں۔ یہاں یہ نہ کہا جائے کہ جب بچے اور پاگل پر زکوٰۃ، نفقہ وغیرہ واجب ہیں، تو وہ بھی بعض احکام کے مکلف ٹھہرے۔ یہ اس لئے کیونکہ یہ واجبات بچے اور پاگل کے افعال سے متعلق نہیں بلکہ ان کے مال سے ہیں۔ یعنی ان کا مال تکلیف کا محل(object)ہے۔ علاوہ ازیں حدیث میں جو کہا گیا کہ ان سے تکلیف اٹھا لی گئی ہے : حتی یبلغ(جب تک بالغ نہ ہو جائے) اور حتی یفیق)ہوش میں نہ آ جائے)، یہ دونوں اقوال تعلیل کا فائدہ دے رہے ہیں، یعنی بچپن اور بے عقلی نص کی علت ہے، اور اس امر کو ان کے مال میں کوئی دخل نہیں اور یہ اس سے مستثنیٰ نہیں۔ اس بیان سے تعریف کا جامع اور مانع ہونا ظاہر ہوا۔ بندوں کے افعال سے متعلق شارع کا وہ خطاب جو طلب یا اختیار دینے کے بارے میں ہے، اسے ’’خطابِ تکلیف‘‘ سے موسوم کیا جاتا ہے اور بندوں کے افعال سے متعلق شارع کا وہ خطاب جو وضع کے بارے میں ہے، اسے ’’خطابِ وضع ‘‘ کہا جاتا ہے۔
خطابِ تکلیف:
خطابِ تکلیف(حکمِ تکلیفی)میں یا تو کسی فعل کو کرنے کی طلب ہو گی یا کسی فعل کو ترک کرنے کی طلب یا پھر اس میں کسی فعل کو کرنے یا چھوڑنے کا اختیار دیا جائے گا۔ اس کے نتیجے میں احکامِ شرعیہ کی یہ پانچ اقسام منظرِ عام پر آتی ہیں : فرض، مندوب، مباح، مکروہ اور حرام۔ زندگی کے تمام افعال انہی میں محدود ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے :
فرض:
شارع کا خطاب اگر کسی فعل کے کرنے سے متعلق ہو اور یہ طلبِ جازم کے ساتھ ہو، تو یہ فرض یا واجب کہلائے گا۔ فرض اور واجب کے ایک ہی معنی ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں کیونکہ یہ دو لفظ مترادف ہیں۔ یہ کہنا صحیح نہیں کہ جو چیز قطعی دلیل)قرآن اور سنتِ متواترہ) سے ثابت ہے وہ فرض ہے اور جو ظنی دلیل( خبر واحد اور قیاس) سے ثابت ہے وہ واجب ہے۔ یہ اس لئے کیونکہ دونوں ناموں )فرض یا واجب)کی ایک ہی حقیقت ہے اور وہ یہ کہ شارع نے کسی فعل کرنے کی طلبِ جازم کی ہے۔ اس اعتبار سے قطعی دلیل اور ظنی دلیل میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ یہ مسئلہ خطاب کے مدلول سے متعلق ہے نہ کہ اس کے ثبوت سے۔ فرض وہ ہے جس کے کرنے والے کی تعریف کی جائے اور نہ کرنے والے کی مذمت کی جائے یا اس کو چھوڑنے والا سزا کا مستحق ہو۔ فرض کو قائم کرنے کی حیثیت سے، اس کی دو قسمیں ہیں : فرضِ عین اور فرضِ کفایہ۔ ان کے وجوب کے اعتبار سے، ان میں کوئی فرق نہیں کیونکہ دونوں طلبِ جازم کے ساتھ ہیں۔ البتہ ان کو قائم کرنے کی حیثیت سے ان میں یہ فرق ہے کہ فرض عین میں ہر فرد سے ذاتی طور پر فعل سرانجام دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے، جبکہ فرضِ کفایہ میں عمومی طور پر مسلمانوں سے فعل کا مطالبہ کیا گیا ہے، یعنی خطاب کا مقصد معین فعل کی انجام دہی ہے نہ یہ کہ ہر فردِ واحد اسے انجام دے۔ لہذا اگر اس فعل کو بعض مسلمانوں نے سر انجام دے دیا( یعنی فعل کی ادائیگی قائم ہو چکی) تو باقیوں سے اس کا ذمہ ساقط ہو جائے گا۔ البتہ ثواب کے مستحق وہی ہوں گے جنہوں نے اس فعل کو کیا۔ اور اگر اس فعل کو کسی نے انجام نہیں دیا، تو جب تک وہ قائم نہیں ہو جاتا، سب گنہگار رہیں گے، ما سوا وہ لوگ جو اس کی ادائیگی میں مشغول ہیں۔ شارع کی طرف سے کسی فعل کو کرنے کی طلب صیغۂ امر(افعل) کے ساتھ ہو گی یا جو کچھ اس معنی کے قائم مقام ہو۔ پھر اگر کوئی ایسا قرینہ پایا جائے جو فعل کو طلبِ جازم ہونے کا فائدہ دے، تو اس صیغۂ طلب اور قرینۂ جازمہ کے باعث، فعل واجب قرار پائے گا۔ مثال :
﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾24:56 (اور نماز قائم کرو) ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾4:103 (یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے) پہلی آیت میں ﴿ وَأَقِيمُوا ﴾ صیغۂ امر میں ہے اور دوسری میں ﴿ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾صیغۂ امر کا قائم مقام ہے کیونکہ یہ امر کے معنی میں ہے۔ ان دونوں آیات سے نماز کی طلب ثابت ہے مگر جس قرینہ نے اس طلب کو جازم قرار دیا وہ یہ آیت ہے : ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴾74:42-43 (تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے) یوں اس طلبِ جازم سے نماز کی فرضیت سمجھی گئی ہے۔
مندوب:
شارع کا خطاب اگر کسی فعل کو کرنے کے بارے میں ہو لیکن طلبِ جازم کے ساتھ نہ ہو، تو یہ مندوب کہلائے گا۔ مندوب، سنت اور نفل کے ایک ہی معنی ہیں، البتہ اسے عبادات میں سنت و نفل کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرے معاملات پر’’ مندوب‘‘ کا اطلاق ہوتا ہے۔ مندوب وہ ہے جس کے کرنے والے کی تعریف کی جائے اور چھوڑنے والے کی مذمت نہ کی جائے، یعنی کرنے والا ثواب کا مستحق ہو اور چھوڑنے والا سزا کا مستحق نہ ہو۔ شارع کے خطاب میں کسی فعل کو کرنے کی طلب پائی جائے، پھر اس میں کوئی ایسا قرینہ پایا جائے جو طلب کو غیر جازم ہونے کا فائدہ دے، تو اس کے باعث فعل مندوب قرار پائے گا۔ مثال : ’’ صلاۃ الجماعۃ تفضل علی صلاۃ الفرد بسبع وعشرین درجۃ ‘‘(متفق علیہ) (جماعت میں نماز پڑھنا، اکیلے پڑھنے سے ستائیس مرتبہ بہتر ہے )
یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صیغۂ امر کے معنی میں نمازِ جماعت کی طلب فرمائی، مگر اس مسئلے میں ایک ایسا قرینہ موجود ہے جو اسے طلبِ غیر جازم ہونے کا فائدہ دے رہا ہے، وہ انفرادی طور پر نماز پڑھنے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکوت کی دلیل ہے اور اس فعل میں اللہ سے قربت کا حصول، لہذا نمازِ جماعت مندوب) سنت) قرار پائی۔
حرام:
شارع کا خطاب اگر کسی فعل کو ترک کرنے کے بارے میں ہو اور یہ طلبِ جازم کے ساتھ ہو، تو یہ حرام یا محظور کہلائے گا۔ ان دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ حرام وہ ہے جس کے کرنے والے کی مذمت کی جائے اور چھوڑنے والے کی تعریف کی جائے یا کرنے والا سزا کا مستحق ہو۔ شارع کے خطاب میں کسی فعل کو ترک کرنے کی طلب صیغۂ نہی(لا تفعل) میں ہو گی یا جو کچھ اس معنی کا قائم مقام ہو۔ پھر اگر اس میں کوئی ایسا قرینہ پایا جائے جو فعل کے ترک کو طلبِ جازم ہونے کا فائدہ دے، تو اس کے باعث یہ فعل حرام قرار پائے گا۔ مثال : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾17:32 (خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا کیوں کہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے) یہاں صیغۂ نہی ﴿ لَا تَقْرَبُوا ﴾سے طلبِ ترک ثابت ہے، جبکہ ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ اس کے طلبِ جازم ہونے کا قرینہ ہے۔ یوں زنا کا حرام ہونا ثابت ہوا۔
مکروہ :
شارع کا خطاب اگر کسی فعل کو ترک کرنے کے بارے میں ہو مگر طلبِ جازم کے ساتھ نہ ہو، تو یہ مکروہ کہلائے گا۔ مکروہ وہ ہے جس کے چھوڑنے والے کی تعریف کی جائے اور کرنے والے کی مذمت نہ کی جائے، یا جس کا چھوڑنا کرنے سے بہتر ہو۔
شارع کے خطاب میں کسی فعل کو ترک کرنے کی طلب پائی جائے، پھر اس میں کوئی ایسا قرینہ پایا جائے جو اس کو طلبِ غیر جازم ہونے کا فائدہ دے، تو اس کے باعث یہ فعل مکروہ قرار پائے گا۔ مثال : ’’ من کان موسرا ولم ینکح فلیس منا ‘‘(البیھقی) (وہ جو مالدار ہو اور نکاح نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں) یہاں صیغۂ نہی کے معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدم نکاح کو منع کیا ہے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مالداروں کے نکاح نہ کرنے پر سکوت اختیار کیا، جو اس طلب کے غیر جازم ہونے کا قرینہ ہے۔ لہذا مالداروں کے لئے عدم نکاح مکروہ قرار پایا۔
مباح :
شارع کا خطاب جب کسی فعل کو کرنے یا ترک کرنے کے بارے میں اختیار دے، تو وہ مباح کہلائے گا۔ یعنی اس اختیار پر ا کوئی شرعی دلیل ہو۔ یہ اس لئے کیونکہ مباح احکامِ شرعیہ میں سے ہے، یعنی یہ، حکمِ اباحت پر شارع کا خطاب ہے جو ہمیشہ دلیل سے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ قائدہ ہے لا حکم قبل ورود الشرع)شرع کے وارد ہونے سے پہلے کوئی حکم نہیں)۔ لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر وہ فعل جس پر شرع خاموش ہے، یعنی جسے نہ شرع نے حرام قرار دیا ہو اور نہ حلال، تو وہ مباح ہے۔ جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے : ’’ الحلال ما أحل اللّٰہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللّٰہفی کتابہ وما سکت عنہ فھو مما عفا عنہ ‘‘(الترمذی) (حلال وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا ہے اور حرام وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا ہے اور جس پر وہ خاموش ہے وہ معاف ہے) تو اس میں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جس چیز پر قرآن خاموش ہے تو وہ مباح ہے، کیونکہ قرآن کی طرح حدیث میں بھی حرام و حلال کے احکام پائے جاتے ہیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے : ’’ ألا انی أوتیت القرآن و مثلہ معہ ‘‘(أحمد)
(بے شک میں قرآن اور اس کی مثل)سنت) کے ساتھ بھیجا گیا ہوں) پس پہلی حدیث کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس بات پر وحی خاموش ہے تو وہ مباح ہے۔ یہ اس لئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان: الحلال ما أحل اللّٰہ میں ہر وہ چیز شامل ہے جو حرام نہ ہو، چنانچہ اس میں فرض، مندوب، مباح اور مکروہ، سب شامل ہیں کیونکہ یہ سب حلال ہیں، یعنی وحی نے انھیں حرام نہیں قرار دیا۔ جہاں تک حدیث کے دوسرے حصے کا تعلق ہے : وما سکت عنہ فھو مما عفا عنہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں پر سکوت ہے، وہ حلال ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے معاف ہیں اور یہ انسانوں پر اس کی رحمت ہے کہ اس نے، ان کے لئے انہیں حرام نہیں بلکہ حلال قرار دیا۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے : ’’ إن أعظم المسلمین فی المسلمین جرما من سأل عن شیء لم یحرم علی المسلمین فحرم علیھم من أجل مسألتہ ‘‘(مسلم) (مسلمانوں میں سے وہ جو مسلمانوں کے خلاف اپنے جرم میں سب سے بڑا ہے وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں جو مسلمانوں کے لئے حرام نہیں تھی مگر اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ ان پر حرام کر دی گئی) یعنی ایسی چیز کے بارے میں پوچھ جس کی تحریم پر وحی خاموش ہے۔ لہذا ان احادیث میں سکوت سے مراد کسی چیز کی تحریم پر سکوت ہے، نہ کہ حکم شرعی کے بیان پر سکوت۔ یہ اس لئے کیونکہ ایسا کوئی فعل یا چیز ہے ہی نہیں جسے شارع نے بیان نہ کیا ہو، بلکہ وحی میں ہر مسئلے کا حل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے : ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ﴾16:89 (ہم نے ایسی کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کو کھول کھول کر بیا ن کرتی ہے) یہ آیت اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ شرع زندگی کے کسی مسئلے میں خاموش نہیں، بلکہ اس میں زندگی کے تمام افعال اور اشیاء پر حکم موجود ہے اور اس بات پر اعتقاد ایمان کا تقاضا ہے۔ پس دوسری احکامِ شرعیہ کی اقسام کی طرح مباح بھی اپنی دلیل سے ثابت ہوتا ہے۔ مثال : ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾5:2 (جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کھیلو) یہاں احرام کھولنے کے بعد شکار کا حکم دیا جا رہا ہے مگر ایک دوسرے قرینہ کی وجہ سے شکار کھیلنا فرض یا مندوب نہیں، بلکہ مباح ہے۔ وہ قرینہ یہ ہے :
﴿ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾5:1 (حالتِ احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا) شکار کا حکم، خلالِ احرام کی نہی کے بعد آیا ہے، پس احرام کھولنے کے بعد شکار مباح ٹھہرا کیونکہ یہ اپنی اصلی حالت کی طرف واپس لوٹے گا، یعنی احرام سے پہلے والی حالت جس میں شکار مباح ہے۔ نیز یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اگر کسی فعل کے بارے میں کوئی حرج نہ پایا جائے تو وہ فعل خودبخود مباح ٹھہرے گا۔ یا اگر کسی فعل سے حرج اٹھا لیا گیا ہو تو اس کا معنی اجازت ہے۔ یہ اس لئے کیونکہ کسی چیز کی حرمت سے اس کی ضد کا حکم ثابت نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی چیز کے حکم سے اس کی ضد پر تحریم ثابت ہوتی ہے۔ بلکہ رفع الحرج(حرج کا اٹھنا) کسی فرض سے منسلک ہو سکتا ہے جیسے : ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ﴾2:158 (پس بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنے والے پر ان کے طواف کر لینے میں بھی کوئی گناہ نہیں) اس آیت میں، رفع الحرج کے باوجود، حج و عمرہ کے دوران طواف کرنا فرض ہے مباح نہیں۔ اسی طرح رفع الحرج کسی رخصت کے ساتھ بھی منسلک ہو سکتا ہے جیسے : ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ﴾4:101 (جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں) یہاں رفع الحرج کا مطلب اباحت نہیں، بلکہ ایک حالت)سفر) میں قصرِ نماز کی رخصت دی گئی ہے۔ لہذا مباح وہ نہیں ہے جس میں حرج نہ پایا جائے یا جس سے حرج اٹھا لیا جائے، بلکہ مباح و ہ ہے جس کے چھوڑنے یا کرنے کے اختیار(اجازت) کے بارے میں شارع کے خطاب پر کوئی سمعی دلیل پائی جائے۔ مثال : ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ﴾2:223 (تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں اپنی کھیتیوں میں جس طرح چا ہو آؤ) علاوہ ازیں یہ کہنا بھی غلط ہے کہ دورِ جاہلیت کے کئی معاملات اسلام کی بعثت کے بعد بھی جاری رہے اور اسلام نے ان پر خاموشی اختیار کی اور وہ مباح مانے گئے، جبکہ جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، صرف وہی ناجائز ٹھہرے۔ لہذا اصل یہ ہے کہ جب تک شرع کسی بات پر خاموش ہے اور اسے حرام نہیں قرار دیتی، تو وہ جائز ہو گی۔ یہ کہنا اس وجہ سے غلط ہے کیونکہ کسی بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شرع خاموش ہے۔ بلکہ، اس کے برعکس، شرع نے تو حکم کو بیان کر دیا ہے، جو اس صورت میں مباح ہے۔ یہ اس لئے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال کی طرح، بذاتِ خود دلیل ہے اور سنت کا ایک جز، اور سنت قرآن کی طرح ایک شرعی ماخذ ہے۔ لہذا آج جب ہم کوئی ایسا فعل انجام دیتے ہیں جو دورِ جاہلیت میں بھی ہوا کرتا تھا، تو ہم اسے اس حیثیت سے اختیار کرتے ہیں کہ یہ حکم شرعی ہے اور اس کی کوئی دلیل موجود ہے، نہ اس حیثیت سے کہ یہ دورِ جاہلیت کی کوئی رسم یا معاملہ ہے۔