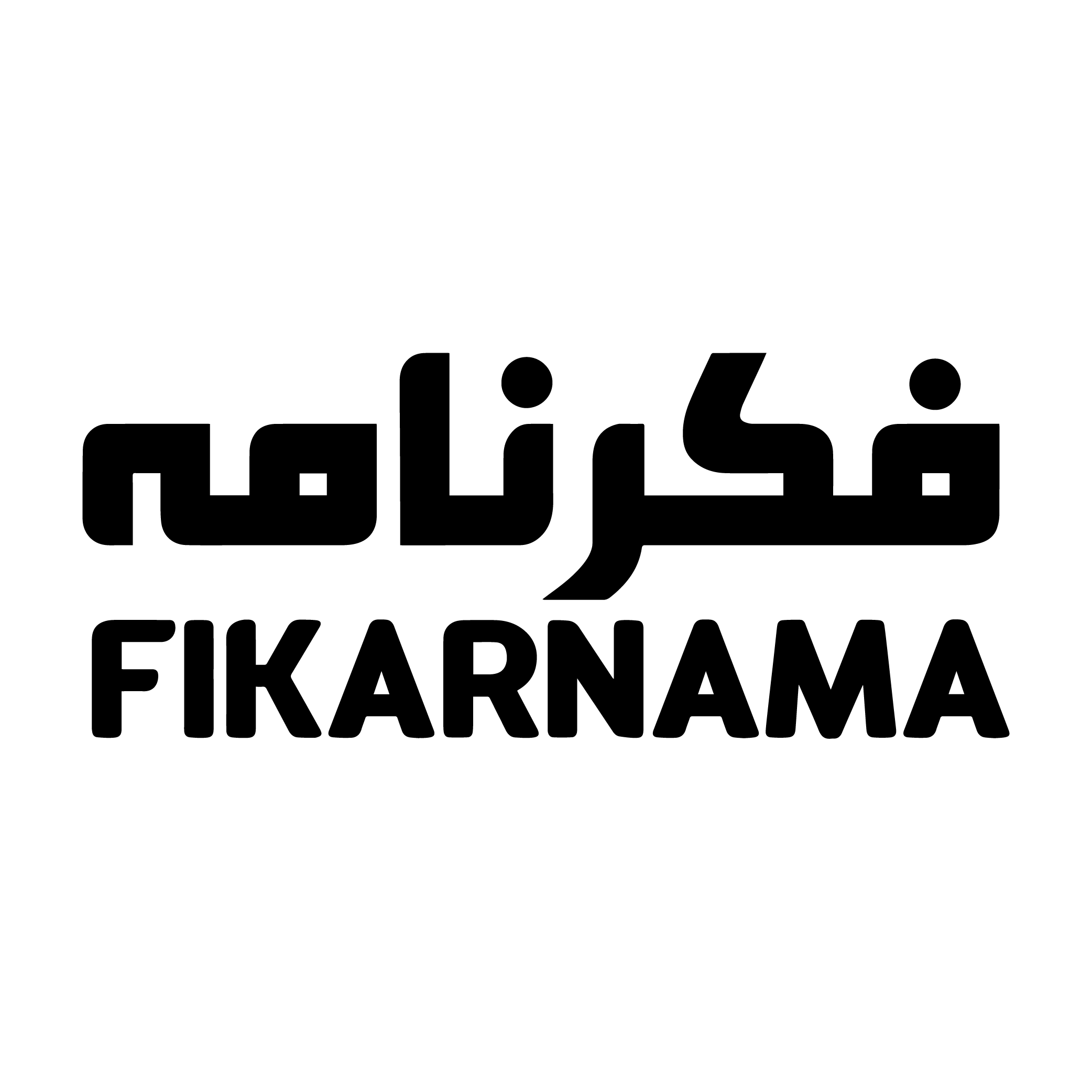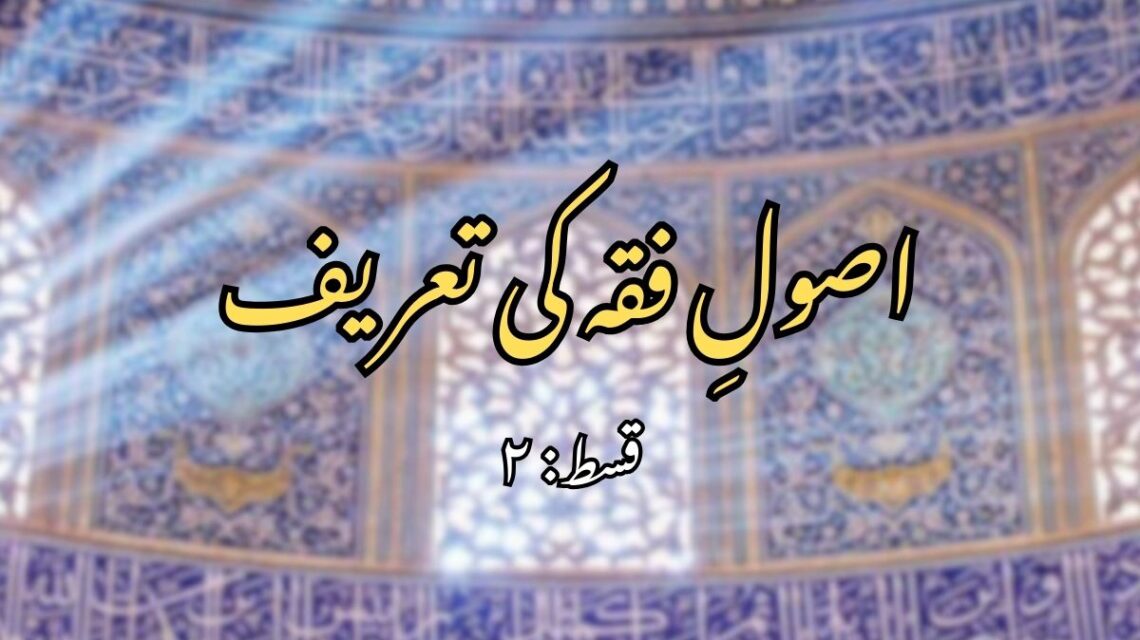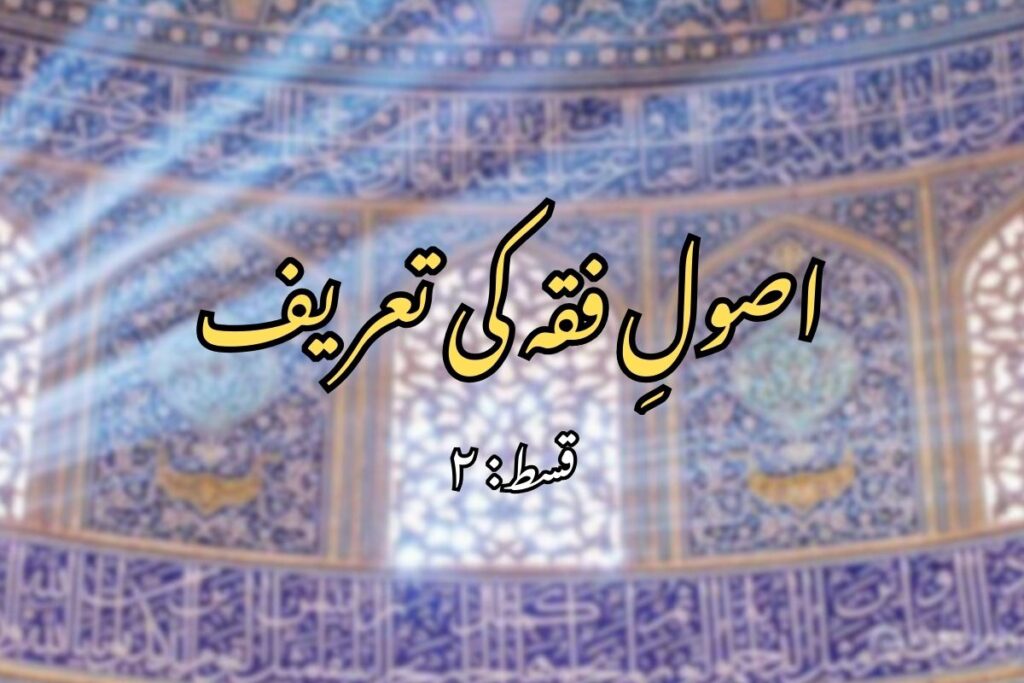
پچھلی قسط میں ہم نے اصول فقہ کی اہمیت اور ضرورت پر بات کی، اس دوسری قسط میں ہم اصول فقہ کی تعریف سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے لیے یہ واضح ہوسکے کہ اصول فقہ کا دائرہ کار کیا ہے۔ اصول فقہ کی تعریف کچھ یوں کی جاتی ہے
معرفۃ القواعد التی یتوصل بھا إلی استنباط الأحکام الشرعیۃ من الأدلۃ التفصیلیۃ
ان قواعد کا علم جن کے ذریعے احکامِ شرعیہ کو تفصیلی دلائل سے مستنبط کیا جائے
اس تعریف سے یہ واضح ہے کہ اس فن میں ساری بحث قواعد پر ہے اور یوں یہ فن علمِ فقہ سے علیحدہ ایک علم ہے کیونکہ فقہ کا دارومدار اور اس کی بحث فروع پر ہے۔ یہ بات اس کی تعریف سے واضح ہے
علم بالمسائل الشرعیۃ العملیۃ المستنبطۃ من أدلتھا التفصیلیۃ
شریعت کے ان عملی مسائل کا علم جو کہ ان کے تفصیلی دلائل سے مستنبط کیے گئے ہوں
لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ علمِ فقہ دراصل علمِ اصولِ فقہ کا نتیجہ ہے اور اس لیے یہ ایک منفرد علم ہے۔ اصولِ فقہ مجتہد کو نصوص سے اللہ کا حکم مستنبط کرتے وقت، ایک خاص طریقۂ کار (methodology) پر پابند رکھتا ہے تاکہ اس کے اجتہاد و استنباط میں وضعداری(consistency) قائم رہے اور وہ ذاتی تخیّل و رغبت سے دور رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے : ﴿ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ﴾پس تم خواہش کی پیروی مت کرو)۔ اصولِ فقہ ان آلات
(tools) کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جن کے ذریعے مجتہد شرعی نصوص سے اللہ کا حکم مستنبط کرتا ہے۔ اس لئے مجتہد کو چاہیے کہ وہ پہلے ان اصولوں کا تعین و اظہار کرے، جن کی مدد سے وہ حکمِ شرعی مستنبط کرے گا تاکہ ہمیشہ اس بنیاد پر، اس کے اجتہاد و استنباط کو پرکھا جا سکے۔
چونکہ حکمِ شرعی کے استنباط سے مراد کسی بات کو اللہ تعالیٰ کا قصد قرار دینا ہے، اس لئے یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، جس میں انتہائی احتیاط اور عمیق( گہری) فکر درکار ہے۔ چنانچہ فقط ایک آیت یا حدیث کو پڑھ کر، اس سے اللہ کا حکم نہیں سمجھا جا سکتا، خواہ بظاہر ایسا لگے. مثال
﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾
(اور اپنے میں سے دو پرہیزگار مردوں کو گواہ کر لو)
﴿ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾
( وہ تم میں سے دو پرہیزگار ہوں یا دوسروں ) کافروں ) میں سے دو)۔
﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾
( اور اپنے میں سے دو مردوں کی گواہی کر لو اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ایک مرد اور دو عورتوں کی)۔
﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا ﴾
(جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر چار گواہ نہ پیش کر سکیں تو انہیں اسی کوڑے لگاؤ اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہ فاسق لوگ ہیں۔ سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں ۔ ’’ أن النبی صلی اللّٰه علیہ وسلم قضی بالیمین مع شاھد الواحد ‘‘نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم اور ایک گواہ)کی بنیاد) پر فیصلہ دیا)۔ جبکہ ایک دوسری حدیث میں، رضاعت کے معاملے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت کی گواہی کو قبول کرنا بھی ثابت ہے۔
یہ تمام نصوص گواہی کے ضمن میں وارد ہوئے ہیں، اب ان سب کو کیسے سمجھا جائے ؟ کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ فقط مسلمان کی گواہی مقبول ہے جبکہ کسی اور جگہ پر کافر کی گواہی کو بھی قبول کیا جا رہا ہے۔ ایک نص میں دو مسلمان مردوں کا مطالبہ کیا گیا ہے جبکہ دوسری میں ایک مرد کی گواہی پر اکتفاء کیا گیا ہے۔ کہیں پر دو عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے جبکہ کسی اور جگہ پر ایک عورت کی گواہی کی مقبولیت ثابت ہے۔ کیا اس کی توبہ کرنے کے بعد قاذف کی گواہی قبول کی جا سکتی ہے یا یہ کبھی نہیں ہو سکتا ؟ اگر نصوص میں تعارض نظر آ رہا ہے تو کس نص کو اختیار کیا جائے اور کس کو رد ؟ اگر ایک نص کو دوسری کا ناسخ قرار دیا گیا ہے تو وہ کس وجہ سے ؟ اور اگر ان تمام نصوص کو جمع کرنا ممکن ہے، تو اس کی کیا کیفیت ہو گی یعنی ان میں تطبیق کیسے پیدا کی جائے گی ؟ وغیرہ۔
ان مسائل کو حل کرنے کے لئے اجتہاد درکار ہے جو مجتہد سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنے اجتہاد میں اصولوں کو اختیار( adopt) کرے، اور جب اس نے ایسا کیا تو وہ اپنے دوسرے اجتہادات میں ان کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اسے انہی اصولوں پر پابند رہنا پڑے گا ورنہ اس کا اجتہاد و استنباط باطل ہو گا کیونکہ ﴿ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ﴾(پس تم خواہش کی پیروی مت کرو)۔ پس اگر اس نے، مثال کے طور پر، کسی مسئلے میں اس اصول کو اختیار کیا ہے کہ حدیثِ مرسل دلیل نہیں ہے، تو یہ کسی اور مسئلے میں اسے بطور حجت استعمال نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر اس نے یہ اصول اپنایا ہے کہ امر وجوب کے لئے ہوتا ہے، تو اسے تمام مسائل میں اس اصول پر قائم رہنا پڑے گا۔ نیز اگر وہ اپنے اصولوں کو تبدیل کرتا ہے، تو اسے ان کا بیان و اظہار کرنا چاہیے تاکہ آئندہ ان نئے اصولوں کی بنیاد پر اس کا محاسبہ ہو سکے۔ اس مختصر بیان سے اصولِ فقہ کی ضرورت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
اصولِ فقہ میں حکمِ شرعی اور اس کی اقسام، دلائل و مآخذ، الفاظ و دلالات اور اجتہاد و تقلید وغیرہ کی بحث شامل ہے۔ آئندہ اقساط میں ان سب کو زیر بحث لایا جائے گا۔